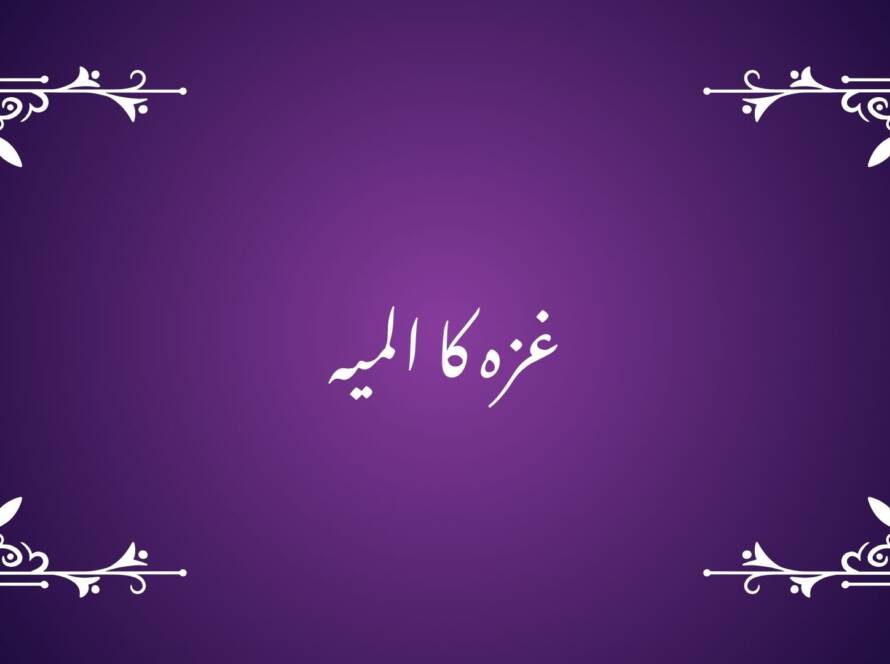تصورِ خدا: علمِ کلام اور فطری استدلال
(محمد حسن الیاس)
مسلمانوں کی علمی روایت میں خدا کے وجود کے اثبات اور اس کی صفات کی تفہیم و توضیح کے حوالے سے دو نمایاں طرزِ فکر سامنے آتے ہیں: ایک وہ جو قرآن کے سادہ، فطری اور وجدانی استدلال پر مبنی ہے، اور دوسرا وہ جو علمِ کلام کی پیچیدہ، تجریدی اور فلسفیانہ تعبیرات سے وابستہ ہے۔
یہ دونوں رجحانات اپنی موجودہ علمی صورت میں دو مستقل زاویوں کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن تاریخی اعتبار سے ان کی نوعیت مختلف ہے۔ قرآنی منہج اپنی اصل میں وحی کا اولین اور بنیادی اسلوب ہے، جبکہ کلامی منہج صدیوں کی فکری جدوجہد اور خارجی فلسفیانہ مباحث کے ساتھ تعامل کا نتیجہ ہے۔ یہاں جو تعارض پیدا ہوا، وہ محض اصطلاحات کا اختلاف نہیں تھا، بلکہ زاویۂ نظر اور طرزِ استدلال کا اختلاف تھا، اور یہی اختلاف بعد میں انسانی شعور کے باطن میں اتر کر ایمان کے ذوق اور فہم کی نوعیت بدلنے لگا۔
پہلا زاویۂ نظر فطری استدلال پر مبنی ہے، جو انسانی شعور، وجدان، تجربے اور مشاہدے کو بنیاد بناتا ہے، جب کہ دوسرا رجحان فلسفیانہ قیاسات، عقلی موشگافیوں اور کلامی اصطلاحات کے ذریعے حقائق کو پیچیدہ منطقی قضایا میں ڈھال کر ثابت کرتا ہے۔ یوں مسئلہ صرف یہ نہیں رہتا کہ کیا ثابت کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ بھی کہ کیسے ثابت کیا جا رہا ہے۔ یہی وہ طرزِ فکر ہے جسے علمِ کلام کے مؤیدین نہ صرف دینی مقدمات کے ثبوت کی اولین فکری بنیاد قرار دیتے ہیں بلکہ اسلامی علوم کی پوری عمارت کو بھی اسی پر استوار سمجھتے ہیں۔
ان کے نزدیک جیسے فقہ انسانی افعال سے متعلق شرعی احکام کو منظم کرتی ہے، اور اصولِ فقہ ان احکام کے استنباط کے لیے ایک نظریاتی سانچہ فراہم کرتی ہے، اسی طرح عین اسی نوعیت کے ساتھ علمِ کلام ایمان کے مقدمات، عقائد کی تعریفات، اور تصورِ الوہیت و رسالت کی تشکیل میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے مطابق تفسیر، حدیث اور فقہ جیسے علوم، وحی کی نوعیت، نبوت کی حقیقت، انسانی فعل کی ذمہ داری، اور خدا کے افعال کی حکمت جیسے بنیادی سوالات کے جوابات علمِ کلام ہی سے اخذ کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ عقل و نقل کے باہمی تعلق، جبر و اختیار کی کشمکش، اور خیر و شر کی فکری تعیین میں فیصلہ کن معیار علمِ کلام کی منہاج کو قرار دیتے ہیں۔
علمِ کلام کے حق میں یہ تصور اس تاریخی پس منظر سے بھی جڑا ہوا ہے جس میں مسلم تہذیبی فکر کو پہلی بار منظم فلسفیانہ چیلنجوں کا سامنا ہوا۔ جب مسلمانوں کا سامنا یونانی فلسفے، منطق اور الحادی اعتراضات سے ہوا تو عقل و وحی کے تعلق کو منظم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور اسی سے علمِ کلام کے مختلف مکاتب وجود میں آئے۔ اس پس منظر میں ایک فریق نے موقف اختیار کیا کہ عقل ایمان کی راہ میں معاون ہے، مگر بنیادی میزان وحی ہی ہے؛ عقل وحی کی معرفت کا ذریعہ ہے، حاکم نہیں۔ اس کے برعکس دوسرے فریق نے عقل کو ماخذِ اوّل قرار دیا اور حسن و قبح، عدل و ظلم اور توحید جیسے بنیادی تصورات کے تعین میں اسے خود مختار مانا، جبکہ وحی کو اس کی تصدیق و تکمیل کا ذریعہ سمجھا۔ یوں علمِ کلام کے دو بڑے رجحانات سامنے آئے، اور رفتہ رفتہ اس علمی منہج کی سمت فطرت، شعور اور قرآنی شہادت کے سادہ اسلوب سے ہٹ کر ایک فلسفیانہ و منطقی طرز پر مرکوز ہوتی گئی۔
یہ فلسفیانہ تشکیل جتنی بھی منظم دکھائی دیتی ہو، ایمان کے مقدمے کو اس کے فطری اور وجدانی تناظر سے ایک بالکل مختلف سمت میں لے جاتی ہے۔ یہاں سے دونوں مناہج کا اصل فرق خود بخود نمایاں ہونے لگتا ہے، کیونکہ ایک طرف ایمان کو انسان کے زندہ تجربے، مشاہدے اور داخلی شعور کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اسے فلسفیانہ تصورات، تجریدی مقدمات اور ما بعد الطبیعیاتی قضایا کی صورت میں مرتب کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ علمِ کلام کا طرزِ استدلال اگرچہ اپنی ظاہری ترتیب اور منطقی ساخت میں سائنسی اور ریاضیاتی طور پر منظم دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ دین کے اس وجدانی، فطری اور انسانی شعور سے وابستہ اسلوبِ دعوت سے بالکل مختلف ہے جس کی بنیاد خود قرآن نے رکھی اور جسے رسول اکرم ﷺ اور ان کے صحابہ نے اختیار فرمایا۔
یہ فرق اس وقت پوری وضاحت کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے جب ہم ایمان کے مقدمے کو کائنات کے سب سے قریب ترین تجربے، یعنی انسان کی تخلیق میں دیکھتے ہیں۔ بے جان غذائی عناصر کا نطفہ بن جانا، اور پھر اس نطفے کا بیضے کے اتصال سے ایک غیر مرئی مرحلے سے گزرتے ہوئے نو ماہ میں شعور و ارادہ رکھنے والی ہستی میں ڈھل جانا، یہ پورا سفر محض مادے کی کیمیائی صفات کا ظہور نہیں بلکہ ایک ارادی، علیم و حکیم فاعل کی قطعی شہادت ہے۔ یہاں دلیل کی زبان غیر ضروری ہو جاتی ہے؛ واقعہ خود بولتا ہے۔ خلق کا یہ مسلسل اور منظم فعل ہمارے سامنے علم، ارادہ اور قدرت کی زندہ گواہی بن کر برپا ہے۔
اسی حقیقت کو اگر ایک اور زاویے سے دیکھا جائے تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان فی نفسہٖ مخلوق ہے۔ مذہب کا مقدمہ بھی دراصل اسی سادہ وجودی حقیقت سے شروع ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری غذا کے بے جان عناصر نطفے تک کیسے منتقل ہوتے ہیں، نطفہ کس طرح انسان بن جانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، اور بیضے کے اتصال کے بعد ایک نہ دکھائی دینے والی حقیقت کس طرح شعور، ارادہ اور شخصیت کی حامل ہستی میں بدلتی ہے۔ سب مراحل آنکھوں کے سامنے ہیں، اور پھر بھی ہم خوب جانتے ہیں کہ نہ غذا میں انسان پوشیدہ تھا، نہ مٹی میں، نہ ان کی کیمیائی ساخت میں کوئی ایسی قوت تھی جو خودبخود مادہ کو حیات اور حیات کو شعور میں بدل دے۔ یہ سب کچھ تخلیق ہے، اور تخلیق کا یہی فعل اعلان کرتا ہے کہ انسان مخلوق ہے۔
اور جب انسان خود کو مخلوق کے طور پر پہچان لیتا ہے تو اس کا اپنا شعور اسے اندر سے مائل کرتا ہے کہ وہ اپنے خالق کی تلاش کرے۔ یہ تلاش اس وجہ سے نہیں کہ ہر چیز کا خالق ہونا چاہیے، بلکہ اس لیے کہ ہر مخلوق کا خالق ہونا ضروری ہے۔ اثر کے لیے مؤثر اور فعل کے لیے فاعل کی اضطراری طلب انسان کی فطرت میں رچی بسی ہے؛ وہ اسے قرار نہیں لینے دیتی جب تک مخلوق سے خالق تک کا ربط کسی نہ کسی سطح پر واضح نہ ہو جائے۔ اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں ایمان کی اصل ساخت نمایاں ہو جاتی ہے، وہ ساخت جو فطرت کے وجدان، شعور کی گہرائی اور انسانی تجربے کی سادگی سے بنتی ہے، نہ کہ پیچیدہ فلسفیانہ مقدمات اور کلامی قضایا سے۔
لیکن مسلمانوں کی علمی تاریخ کی تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں ایک ایسا مرحلہ آیا جب یہی سادگی، یہی براہِ راست تجربہ اور یہی فطری قربت آہستہ آہستہ پس منظر میں دبنے لگی۔ بیرونی فلسفیانہ دباؤ بڑھا تو توجہ اس فطری استدلال سے ہٹ کر ایک دفاعی، منطقی اور فلسفیانہ طرزِ استدلال کی طرف منتقل ہونے لگی۔ اعتراضات کا جواب دینا تھا، مگر ضرورت اس بات کی تھی کہ جواب اپنے میدان میں دینے کے ساتھ مخاطب کو اس استدلال تک بھی واپس لایا جاتا جس کی بنیاد انسان کے اندر پہلے سے موجود بدیہی حقیقتوں اور فطری شہادتوں پر رکھی گئی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان کی فطری زبان، جسے قرآن نے انسانی شعور کے قریب ترین رکھا تھا، غیر محسوس طریقے سے پس منظر میں سرکتی گئی اور اس کی جگہ فلسفیانہ تعبیرات اور منطقی اسالیب نے لے لی۔
یہی فکری پس منظر وہ بنیاد بنا جس پر بعد کے زمانوں میں علمِ کلام کی منظم عقلی عمارت وجود میں آئی۔ متکلمین کا یہ ڈھانچہ خلا میں نہیں بنا تھا؛ یونانی منطق، نیوپلاٹونزم اور دہری یا حلولی اعتراضات کے جواب میں یہ علمی تشکیل سامنے آئی۔ اور رفتہ رفتہ دفاع اصل پر غالب آگیا اور وسیلہ مقصد بن گیا۔یوں یہ دفاعی منہج اصل دعوت پر چھا گیا اور فطری استدلال حاشیے پر چلا گیا۔ یہ فرق صرف طرزِ استدلال کا نہیں تھا بلکہ ایمان کی معنویت اور اس کے ذوق پر براہِ راست اثر ڈالنے والا فرق بن گیا۔
چنانچہ علمِ کلام کے مباحث میں ایسے مسائل مرکزیت اختیار کر گئے جن کا دین کی اصل دعوت، اس کی روح اور اس کے اخلاقی مقاصد سے براہِ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔ امکانِ کذبِ باری، تعددِ قدیم بالذات، اور حوادث لا أول لها جیسے سوالات دراصل انہی فلسفیانہ مقدمات کی پیداوار تھے جو وجود، تخلیق اور صفاتِ الٰہی کے عقلی تجزیے سے متعلق تھے۔ خدا کے وجود کے اثبات کے لیے علمِ کلام کی مرکزی دلیل “دلیلِ حدوثِ عالم” بظاہر مضبوط عقلی قیاس ہے، مگر اس کا پہلا مقدمہ ہی محلِ استدلال ہے کہ عالم حادث ہے۔ جب دلیل کا بنیادی مقدمہ ہی قطعی نہ ہو تو وہ دلیل جسے فیصلہ کن برہان سمجھا گیا، خود غیر محکم رہتی ہے۔ لہٰذا خالق کے وجود پر استدلال کا مقدمہ، خود اپنے ثبوت کا محتاج بن جاتا ہے، اور یوں پوری کلامی عمارت ایک دوہری غیر یقینی میں الجھ جاتی ہے۔
فلسفہ چونکہ وجود کے مراتب اور ان کی تعریفات سے شروع ہوتا ہے، اس لیے واجب الوجود، ممکن الوجود، قدیم بالذات، حادث بالذات جیسے تصورات وضع ہوئے، جن کی بنیاد محض تجریدی عقل اور تخیل ہے۔ انہی مقدمات سے وہ سوالات پیدا ہوئے کہ اگر خدا قدیم بالذات ہے تو اس کی صفات بھی قدیم ہوں گی یا حادث؟ اگر کلامِ الٰہی حادث ہے تو کیا وہ مخلوق قرار پائے گا؟ علمِ کلام نے ان سوالات کو دفاعی طور پر قبول کر کے مذہبی نصوص کی تاویلوں کے ساتھ ایک وسیع منطقی و فلسفیانہ عمارت کھڑی کی، جس کی بنیاد قرآن کے فطری شعورِ ایمان میں نہیں بلکہ یونانی فلسفے کے سوالات میں تھی۔
نتیجہ یہ ہوا کہ خدا پر ایمان، جو قرآن میں ایک تجرباتی، وجدانی اور فطری حقیقت ہے، ایک تجریدی منطقی قضیہ بن کر رہ گیا۔ ایمان، جو ایک زندہ لمحۂ تسلیم تھا، ایک نظری بحث میں تبدیل ہو گیا۔ یقین کی جگہ عقلی تصدیق نے لے لی، اور تسلیم کی جگہ تشکیک پیدا ہونے لگی۔ ایمان کی اصل کیفیت تعلق، حضوری اور خضوع، نظری تعبیرات میں تحلیل ہو کر رہ گئی۔
اس کے برخلاف قرآن کا منہج نہایت سادہ، وجدانی اور براہِ راست ہے۔ وہ خدا کے وجود کو نہ کسی فلسفیانہ تعریف کا محتاج بناتا ہے، نہ ما بعد الطبیعیاتی مقدمات کا۔ وہ انسان کے شعور اور فطرت کو براہِ راست مخاطب کرتا ہے۔ ارشاد ہوا
“أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ”
کیا اس خدا میں شک ہو سکتا ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟
یہ دلیل کی رسمی ساخت نہیں، بلکہ وہ وجدانی ندا ہے جو انسان کے اندر پہلے سے موجود فطری شعور کو جگاتی ہے۔
اسی طرح:
“أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ
أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ”
“بتاؤ جو نطفہ تم ڈالتے ہو،
کیا اسے تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟”
اور:
“أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ”
کیا وہ اونٹ کی تخلیق پر غور نہیں کرتے؟
یہاں نہ واجب الوجود کی اصطلاح ہے، نہ قیاسِ منطق۔ صرف مشاہدہ، تجربہ اور فطرت ہے، اور انہی کے ذریعے خدا کی پہچان۔
چنانچہ قرآن خدا کو رب کے طور پر پیش کرتا ہے: وہ ہستی جو پیدا کرتی ہے، پالتی ہے، سنبھالتی ہے، رہنمائی دیتی ہے، اور ہر لمحہ انسان کی زندگی میں موجود ہے۔ یہ خدا کا وہ تصور ہے جو صرف ایک ماورائی وجود نہیں بلکہ ایک ذاتی، زندہ، حاضر و ناظر تعلق کی شکل میں سامنے آتا ہے، جو انسان کے اندر شکر، محبت، خوف اور امید پیدا کرتا ہے۔
قرآن نے تخلیقِ انسان کے تکوینی مراحل بیان کر کے بتا دیا کہ کائنات کا یہ ظہور ایک علیم و حکیم ارادہ کی کارفرمائی ہے:
“بَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَاءٍ مَّهِينٍ، ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ”
یہاں حیاتی مرکبات سے شعور تک کے سفر میں ربوبیت کی مسلسل نگرانی دکھائی گئی ہے؛ یہ مشاہدہ خود انسان کو اس علیم و حکیم خالق کی طرف لے جاتا ہے۔
فطری استدلال دراصل اس روشنی کا نام ہے جو انسان اپنے اندر ازخود پاتا ہے۔ خیر و شر، عدل و ظلم اور حسن و قبح کی پہچان اسے کسی منطق یا فلسفے سے نہیں ملتی بلکہ یہ اس کے شعور میں بدیہی سچائیوں کی صورت میں ودیعت ہوتی ہے۔ یہی داخلی شہادت اس کے لیے بنیادی مقدمات بناتی ہے، اور انہی مقدمات سے وہ اس حقیقت تک پہنچتا ہے کہ کائنات کا یہ نظم، یہ اخلاقی احساس اور یہ شعوری زندگی کسی اندھے مادے کا کھیل نہیں ہوسکتے۔ یہاں دلیل انسان پر باہر سے مسلط نہیں کی جاتی بلکہ اس کا اپنا باطن اسے دلیل فراہم کرتا ہے۔ فطری استدلال دلیل کو پیچیدہ مقدمات میں تبدیل نہیں کرتا بلکہ اسے ان سچائیوں تک پہنچنے کا سادہ راستہ بنا دیتا ہے جو پہلے ہی انسان کے اندر گواہی دے رہی ہوتی ہیں۔ اسی لیے اس میں دلیل بوجھ نہیں بنتی بلکہ فطرت کی تصدیق بن جاتی ہے۔
اس فطری، وجدانی اور تجربی اسلوب کی یہی قوت ہے جس نے ہر دور میں ایمان کی بنیاد قائم رکھی ہے، اور یہی وہ بنیاد ہے جسے بعد کی فلسفیانہ پیچیدگیوں سے الگ رکھ کر سمجھنے کی ضرورت ہمیشہ محسوس کی گئی۔ ہمارے معاصر علمی تناظر میں استادِ مکرم جناب جاوید احمد غامدی علمِ کلام کی افادیت پر نقد کرتے ہوئے اسی فطری استدلال کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور ایمان کے مقدمے کو دوبارہ فطرت اور وجدانی شعور کے دائرے میں قائم کرتے ہیں۔
ان کے نزدیک فطری استدلال کی بنیاد یہ ہے کہ انسان خیر و شر، عدل و ظلم اور حسن و قبح کا ادراک اپنے اندر پاتا ہے۔ یہ ادراک اضطراری ہوتا ہے اور یہی اقدار اسے اس ہستی کی طرف متوجہ کرتی ہیں جو ان کا سرچشمہ ہو۔ اسی شعور سے ایمان کی ابتدا ہوتی ہے، کیونکہ وجودی حقائق کی یہ پہچان کسی بیرونی دلیل کی محتاج نہیں رہتی۔ “آفتاب آمد دلیلِ آفتاب” کی طرح انسان اپنے اندر پائی جانے والی اس بدیہی شہادت سے براہ راست خدا کی ضرورت تک پہنچ جاتا ہے۔
اس کے بعد عقل جہاں تک پہنچ سکتی ہے وہاں تک اپنا کام کر دیتی ہے، لیکن ہدایت کی تکمیل کے لیے وحی ناگزیر ثابت ہوتی ہے۔ غامدی صاحب کے مطابق فطری استدلال ہمیں خدا کے وجود کی ضرورت تک پہنچا دیتا ہے، لیکن خدا کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی مشیت اور مرضیات کیا ہیں، اور انسان کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت کیا ہے، یہ وہ حقائق ہیں جو عقل کے دائرے سے باہر رہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ “لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ”، یعنی نفس اور مادے سے آگے کی معرفت تک رسائی صرف اسی سلطان کے ذریعے ہو سکتی ہے جس کا نام وحی ہے۔ فطری شعور بنیاد فراہم کرتا ہے اور وحی اس بنیاد کو آخری منزل تک پہنچا دیتی ہے اور انسان کو ان بحثوں سے محفوظ رکھتی ہے جن کا تعلق عقل کی حدود سے باہر کی دنیا سے ہے۔
یوں فطرت، تجربہ، عقل اور وحی مل کر ایمان کی اس ہم آہنگ ساخت کو وجود دیتے ہیں جو نہ فلسفیانہ تجرید کی محتاج ہے، نہ مناظرانہ کلام کی۔ یہ ایمان اپنے مرکز میں سادہ، فطری اور انسانی ہے وہ ایمان جو انسان کو خالق کے ساتھ زندہ تعلق میں داخل کرتا ہے اور اسی تعلق کو تمام علم و اخلاق اور تہذیب کی بنیاد بنا دیتا ہے۔
قرآن کا یہی اسلوب اسے تمام مکاتبِ فکر سے ممتاز کرتا ہے۔ وہ انسان سے فلسفی بننے کا مطالبہ نہیں کرتا بلکہ انسان ہونے کے اس بنیادی شعور تک لوٹنے کی دعوت دیتا ہے جہاں فطرت خود اس کی رہنما اور دلیل بن جاتی ہے۔ وہ عقل کو اس کے مقام پر قائم رکھ کر فطرت کی روشنی میں اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور دلیل کو تصوراتی پیچیدگیوں کا بوجھ نہیں بننے دیتا بلکہ اسے اس سادہ اور براہِ راست حقیقت تک پہنچنے کا وسیلہ بناتا ہے جس کی گواہی انسان کے اندر پہلے ہی روشن ہوتی ہے۔ اسی لیے اس کا خطاب دہقان اور چرواہے سے لے کر تاجر اور معلم تک، اور صاحبِ علم اور مفکر سے لے کر فلسفی اور بزرگ تک ہر انسان تک یکساں گہرائی اور قوت کے ساتھ پہنچتا ہے۔ وہ کسی فنی اصطلاح، منطقی موشگافی یا نظریاتی آفاق تجرید پر تکیہ کیے بغیر براہِ راست انسان کے شعور سے ہم کلام ہوتا ہے۔
اور یہی اس کا اعجاز ہے کہ وہ محض ایک فکری متن نہیں بلکہ “ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ” اور کتابِ منیر ہے, وہ نور جو ہر زمانے، ہر معاشرے اور ہر انسان کے لیے یکساں طور پر راہِ ہدایت کھول دیتا ہے، اور جس کی صداقت، سادگی اور قدرتِ بیان کسی انسانی کلام میں ممکن ہی نہیں۔